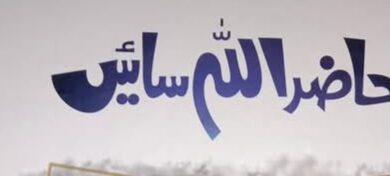علما اور جہاد
(خورشید ندیم)
”علما دوسروں کو جہاد کے لیے کہتے ہیں‘ خود جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ مذہبی راہنما دوسروں کے بچوں کو مرواتے ہیں مگر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں یا بیرونِ ملک پڑھاتے اور انہیں ایک آسودہ زندگی دیتے ہیں۔ یہ انہیں جہادی کیوں نہیں بناتے؟‘‘
اس نوعیت کے اعتراضات اکثر سننے میں آتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ سوالات جس مقدمے پر مبنی ہیں‘ وہ تفہیمِ نو کا محتاج ہے۔ یہ مقدمہ ادھوری سچائی کو بیان کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ علما کے سماجی کردار کے باب میں سوئے فہم ہے۔ اس سوئے فہم کو پیدا کرنے کا سبب بھی علما خود ہیں۔ وہ اپنے سماجی کردار کوجس طرح توسیع دیتے ہیں‘ اس کے بعد ان سوالات کا پیدا ہونا ناگزیر ہے۔
علما مسلم سماج کی ضرورت ہیں۔ اسلام کا تصورِ حیات خدا کی بندگی اور آخرت میں جوابدہی کی اساسات پر کھڑا ہے۔ یہ اپنی روح میں انفرادی ہے۔ ہر فرد کو ذاتی حیثیت میں اپنے رب کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہو جو دین کے اس بنیادی مطالبے کی طرف عوام کو متوجہ کرتا رہے تاکہ ان کو یاددہانی ہوتی رہے۔ انبیا بھی اصلاً اسی تذکیر کے لیے مبعوث کیے جاتے رہے۔ ختم نبوت کے بعد انذار کی یہ ذمہ داری اس امت نے اور پھر اس کی نمائندگی کرتے ہوئے علما نے سر انجام دینی ہے۔ انبیا چونکہ اپنے پروردگار سے براہِ راست راہنمائی لیتے ہیں‘ اس لیے انہیں دین سیکھنا نہیں پڑتا۔ ان کے بعد اب جو طبقہ یہ ذمہ داری ادا کرے گا‘ اُس کے لیے لازم ہے کہ پہلے تفقہ فی الدین حاصل کرے۔ یعنی عالم بنے اور اس کے بعد یاددہانی کی ذمہ داری ادا کرے۔ یہ بات سورۂ توبہ میں بیان کر دی گئی ہے۔
سادہ لفظوں میں مسلم سماج سے یہ دین کا مطالبہ ہے کہ ان میں ایک گروہ ایسا ہو جو عالم بنے اور تمام سماجی طبقات کو ان کی دینی ذمہ داری کے بارے میں متنبہ کرے اور انہیں روزمرہ زندگی کے امور سرانجام دینے کے لیے دین کا علم سکھائے۔ جو عالم یہ کام کر رہا ہے‘ وہ شرعاً مزید کسی ذمہ داری کا مکلف نہیں ہے۔ گویا اس کا کام جہاد نہیں ہے۔ اس میں ایک استثنا ہے اور وہ ہے نظمِ اجتماعی کی طرف سے نفیرِ عام۔ اگر حکومت یہ اعلان کرتی ہے کہ سب شہری جہاد کے لیے نکلیں تو پھر علما بھی دوسروں کے ساتھ پابند ہوں گے کہ جہاد کے لیے نکلیں۔ موجودہ دور میں‘ جب عسکری خدمات کے لیے باضابطہ افواج ہوتی ہیں‘ یہ امکان بھی باقی نہیں رہا۔ اس وجہ سے میری گزارش یہ ہے کہ جب علما سے جہاد میں حصہ لینے کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو وہ غیر ضروری ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی سپاہی سے یہ کہا جائے کہ وہ بچوں کو پڑھاتا کیوں نہیں یا کسی سرکاری ملازم سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ بندوق کیوں نہیں اٹھاتا۔
علما کا لیکن اپنے بارے میں یہ خیال نہیں‘ الا ماشاء اللہ۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا کردار محدود نہیں ہے۔ وہ سیاست کریں گے۔ وہ کاروبار کریں گے۔ وہ اقتدار میں بھی حصہ دار ہوں گے۔ انہیں کسی ایک شعبے کا پابند نہیں رکھا جا سکتا۔ سیاست کے بارے میں وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ انبیا کا وارث ہونے کی وجہ سے یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ جب علما نے خود ہی اپنا دائرہ کار بڑھایا تو اب لوگ ان سے یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ آپ تمام کام کر سکتے ہیں تو جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اپنے بچوں کو اس معرکے میں کیوں نہیں اتارتے جس میں جان کے زیاں کا امکان ہے؟ جب سب کام کرتے ہیں تو جہاد کیوں نہیں؟ اس کے لیے دوسروں کے بچے ہی کیوں؟
ہماری روایت میں علما نے خود کو تعلیم وتعلم اور دعوت وانذار تک محدود رکھا تھا۔ شریعت نے انہیں دوسروں کاموں سے روکا نہیں۔ وہ سب کام کر سکتے ہیں‘ البتہ وہ ان کے لیے مکلف نہیں ہیں۔ اگر وہ اپنا اصل کام نہیں کریں گے تو اس کے لیے جوابدہ ہوں گے اور وہ ہے انذار۔ ہماری تاریخ یہ ہے کہ علما اپنی حدود سے بخوبی واقف رہے ہیں۔ انہوں نے خود کو دوسرے کاموں سے دور رکھا۔ اپنے معاش کے لیے تجارت کی لیکن اصل کام کو ترجیح دی۔ اگر انہیں اقتدار یا سیاست میں شرکت کی دعوت دی گئی تو ان میں سے اکثر نے اس پر آمادگی ظاہر نہیں کی۔ سیاسی معاملات میں ان کی مداخلت بھی انذار ہی کی حد تک تھی۔ حکمرانوں کے ساتھ ان کا تعلق اتنا ہی تھاکہ وہ انہیں ان کی دینی ذمہ داریوں کے بارے میں خبردار کرتے رہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس حوالے انہوں نے عزیمت کا مظاہرہ کیا اور تابندہ روایات قائم کیں۔ تاہم امام ابو یوسفؒ کی طرح کے علما بھی تھے جنہوں نے مناصب قبول کیے مگر اپنے علمی وقار پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ اسی طرح ہنگامی حالات میں بعض علما نے آگے بڑھ کر کردار ادا کیا جیسے امام ابن تیمیہ۔
سیاسی زوال کے بعد‘ مسلمانوں میں احیا کی جو تحریکیں برپا ہوئیں ان کے نتیجے میں علما کا سماجی کردار تبدیل ہوا۔ ان میں ایسی تحریکیں بھی تھیں جنہوں نے دینی اور سیاسی احیا کو ایک دینی فریضہ قرار دیا۔ ان کی قیادت علما کے ہاتھ میں تھی۔ جیسے ہمارے ہاں مولانا ابوالکلام آزاد یا مولانا مودودی۔ جمعیت علمائے ہند کا معاملہ بھی یہی تھا۔ انہوں نے امام ابن تیمیہ کو مثال بنایا۔ مولانا آزاد کے بارے میں شورش کاشمیری مرحوم نے کہا تھا کہ وہ ہندوستان میں ابن تیمیہ تھے۔ اس نسبت کی وجہ بھی یہی علمِ دین اور سیاست کی یکجائی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد علما نے بحیثیت مجموعی اسی روایت کو آگے بڑھایا۔ مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ وہ شیخ الہند کے جانشین ہیں۔ مسلک دیوبند میں سیاسی رجحان غالب رہا۔ جماعت اسلامی تو ہے ہی سیاسی تحریک۔ بریلوی مسلک میں البتہ یہ رجحان دیر سے آیا۔
ان تحریکوں نے ایک نئے طبقے کو جنم دیا جسے ‘ذہبی قیادت‘ کہتے ہیں۔ یہ لوگ معروف معنوں میں عالم نہیں۔ یہ اصلاً سیاستدان ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں۔ ان کو علما پر قیاس کیا جائے یا سیاستدانوں پر؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اگر وہ علما ہیں تو ان کا اصل کام انذار ہے۔ اگر سیاستدان ہیں تو پھر ان کا معاملہ دوسرا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ طبقہ کبھی عالم کے روپ میں سامنے آتا ہے جب مدارس کے تحفظ کے لیے تحریک اٹھاتا ہے اور کبھی سیاستدان بن جاتا ہے جب انتخابات میں حصہ لیتا یا حکومت میں شریک ہوتا ہے۔
علما کے بارے میں یہ عرض کیا جا چکا کہ مسلم معاشرے میں ان کا کردار متعین ہے۔ اگر وہ اس دائرے میں محدود رہیں تو انہیں ان سوالات اور اعتراضات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن اگر وہ اس کو زندگی کے دیگر شعبوں تک توسیع دیں گے تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ ان میں جہاد کیوں شامل نہیں؟ پھر اس سوال کو نظر انداز کرنا بھی آسان نہیں ہوگا کہ آپ کے بچے ایسی جنگوں کا ایندھن کیوں نہیں بنتے؟ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔
ایک سوال علما کے عمومی رہن سہن اور امیرانہ اندازِ زندگی کے بارے میں بھی اٹھتا ہے۔ ان کے ذرائع آمدن بھی زیرِ بحث آتے ہیں۔ اس وقت مگر یہ میرا موضوع نہیں۔ امارت اور علم کی یکجائی اور اس کے جواز وعدم جواز پر کسی اور کالم میں بات ہو گی۔ اس وقت میں نے خود کو اس صرف اس سوال تک محدود رکھا ہے کہ دینی نقطہ نظر سے علما کا کردار کیا ہے؟ میں نے واضح کرنے کی کوشش کی کہ اصلاً یہ انذار ہے۔ اگر وہ اس کے علاوہ کچھ کریں گے تو اسی حوالے سے سوالات بھی پیدا ہوں گے۔ پھران سوالات کے جواب دینا ان پر لازم ہو گا۔